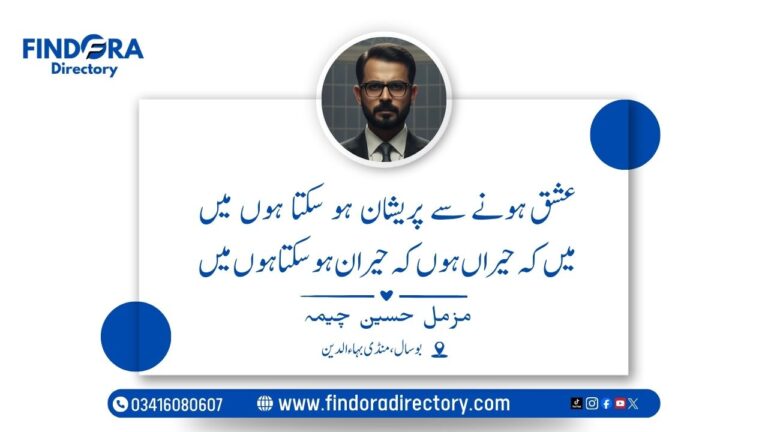شاعری: ایک لاعلاج بیماری …. تحریر: مزمل حسین چیمہ
Similar places
دلِ خراب نے باندھا ہے ڈورِ وحشت سے یہی تعلقِ دیرینہ ہے طبیعت سے ہر ایک کو جو جتانے لگے
عشق ہونے سے پریشان ہو سکتا ہوں میں میں کہ حیراں ہوں کہ حیران ہو سکتا ہوں میں خود شناسی
باوجود اس کے یہ جہاد نہیں عشق کو عشق کہہ فساد نہیں بس تمہیں چومنا لطافت ہے چومنے میں کوئی
اُچ شریف کے خواب واقعی اُچّے ہیں، اس قدر اُچّے کہ بعض اوقات خود اُچ شریف بھی اُنہیں دیکھ کر
خواب کے رنگ میں پوشیدہ حقیقت ہے کوئی تیری آنکھوں میں چھپی میری محبت ہے کوئی تیرا چہرہ مرے خوابوں
میری آنکھوں کو دود کر گئی ہے عمر بھر کا قیود کر گئی ہے ہجر آلود گفتگو تیری ریزہ ریزہ
ترے بغیر مجھے جینے کا مزہ ہی نہیں کہ میرے دل میں بچھڑنے کا حوصلہ ہی نہیں تمہارا ہونا سمندر
تو ہوش میں ہے ، کسی طور بدحواس نہیں اداس لڑکی! تری آنکھیں تو اداس نہیں تمہارے جسم پہ یہ
دلِ دیوانہ کو بازار بنانے والے ہم تری راہ کو گلزار بنانے والے پانی میں آگ لگا دیں گے ضرورت